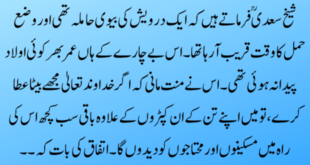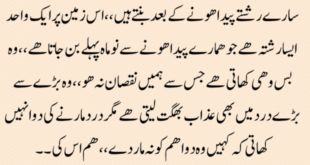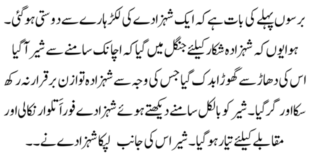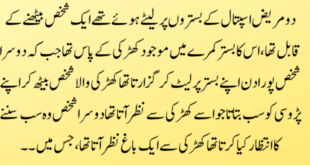جب میں نے برمنگھم میں سکول میں داخلہ لیا تو میرے ساتھی طالب علموں کے پاس مجھ سے پوچھنے کے لیے کافی سوالات تھے۔ ‘آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟’ ‘آپ کو کیا ہوا ہے؟’ ‘آپ کے چہرے کو کیا ہوا ہے؟’ اور یہ سب میرے چہرے پر موجود زخموں کے رہ جانے والے نشانات کے سبب تھا۔ پاکستان میں میرے ساتھ جو ہوا تھا میں اس کو چھپا نہیں سکتا تھا، اور میں ایسا کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ یہ نشانات میرے چہرے کی دائیں جانب اور میرے منہ کے عین اوپر ہیں۔ ابتدا میں ان کی موجودگی سے میں بہت متاثر ہوا کیونکہ جب روزانہ میں آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا تو میرے ساتھ پیش آیا واقعہ میرے ذہن میں گھوم جاتا۔ مجھے یہ کافی مشکل لگتا تھا کہ ہر کسی کو انفرادی طور پر بار بار بتاتا کہ میرے چہرے پر نشانات کیوں ہیں اور یہ کیسے بنے۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ ایک ہی مرتبہ سب کو اپنی کہانی بیان کر دوں۔ اس مقصد کے لیے سکول انتظامیہ نے میرے لیے سب کو ایک جگہ اکھٹا ہونے کا کہا۔ بات شروع کرنے سے قبل میرے ہاتھوں پر پسینہ آ رہا تھا جبکہ میری ٹانگیں کپکپا رہی تھیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں اس لیے بہت خوش تھا کہ میرے سامنے موجود پوڈیم میری کپکپاہٹ کو پورے سکول پر عیاں نہیں ہونے دے رہا تھا۔ میرے ساتھ پیش آئے واقعے کے تین برسوں بعد یہ پہلا موقع تھا کہ میں سٹیج پر دوبارہ کھڑا تھا۔ میں نے اپنی تقریر لکھی ہوئی نہیں تھی کیونکہ میں جانتا تھا کہ مجھے کیا کہنا ہے۔ جب میں نے بولنا شروع کیا تو ہال میں موجود افراد مکمل خاموشی اور انہماک کے ساتھ میری بات سن رہے تھے۔ ابتدا میں میں اس قابل نہیں تھا کہ ہال میں موجود افراد کے چہروں کی طرف دیکھوں۔ تاہم بعد میں جب میں نے اپنی نگاہیں اٹھائیں تو کئی طالب علموں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ بعد ازاں میرے اساتذہ نے مجھے بتایا کہ انھوں نے طالب علموں کو کبھی اتنا خاموش نہیں دیکھا جتنا وہ میرے گفتگو کے دوران تھے۔ میں سہما ہوا تھا اور میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس کو دوبارہ یاد کرنا بہت تکلیف دہ تھا۔ میرے ماضی اور ان دوستوں نے جنھیں میں کھو چکا تھا مجھے اس بات پر مجبور کیا تھا کہ میں نے سٹیج پر آؤں اور اپنی کہانی بیان کروں۔ 16 دسمبر 2014 کو جب میں صبح سو کر اٹھا تو وہ عام سا دن تھا۔ میں نے سکول یونیفارم پہنی اور کار پارکنگ میں اپنے دوستوں کو ملا۔ ہماری یہ روٹین تھی کہ سکول شروع ہونے سے قبل ہر روز ہم سکول کیفٹیریا میں اکھٹے ہوتے اور ناشتہ کرتے۔ ہماری گفتگو کا محور عموماً کرکٹ کا گذشتہ روز ہوا میچ ہوتا۔ اس کے بعد ہم اپنی کلاس کا رخ کرتے۔ ہمارا سکول پشاور میں تھا اور یہ آرمی کے زیر انتظام چلنے والا سکول تھا۔ اسی وجہ سے ہم سکول میں فوجیوں کو دیکھ پاتے تھے۔ یہ ہمارے لیے نئی بات نہیں تھی کہ فوج کا کوئی میجر سکول کے آڈیٹوریم میں آ کر ہمیں ابتدائی طبی امداد پر لیکچر دے۔ ہمارے سکول میں مختلف سیکشن تھے جیسا کہ سکول سیکشن، کالج سیکشن اور چھوٹے بچوں کا سیکشن۔ طبی امداد پر لیکچر کے لیے سکول اور کالج ونگز اکھٹے ہوتے تھے اور اس وجہ سے آڈیٹوریم 11 سے 18 سال کے طالب علموں سے کھچا کھچ بھرا ہوتا تھا۔ اس وقت میری عمر 12 برس تھی اور میں سکول ونگ کا سب سے چھوٹا بوائز ہیڈ تھا۔ میرا بوائز ہیڈ ہونا میرے والدین کے لیے قابلِ فخر بات تھی۔ بوائز ہیڈ ہونے کی وجہ سے میں سٹیج پر پرنسپل کے ساتھ بیٹھتا تھا اور اس دن سٹیج پر میجر صاحب بھی موجود تھے۔ سٹیج سے میں تمام طالب علموں کے چہرے دیکھ سکتا تھا۔ میرے دوست میری توجہ مبذول کروا کر بعض اوقات مجھے منہ چڑاتے اور یہ کرتے ہوئے ان کی کوشش ہوتی کہ میں ہنس دوں۔ اس دن ہم بات چیت کے تقریباً درمیان میں تھے جب ہم نے ایک زوردار دھماکہ سنا۔ یہ زوردار تھا تاہم اتنا بھی نہیں۔ چند ہفتوں قبل کالج ونگ کے طالب علموں نے مذاق کرتے ہوئے سکول کے آڈیٹوریم میں پٹاخہ پھینکا تھا۔ ہم نے اسے بہت انجوائے کیا تھا مگر ہمارے اساتذہ کے لیے یہ اتنا خوش کن نہیں تھا۔ آج آنے والی آواز اس دن آئے پٹاخے کے چلنے کی آواز سے مختلف تھی۔ یہ پٹاخہ پھوٹنے کی آواز بالکل نہیں تھی۔ یہ آرمی ڈرل سے آنے والی آواز ہو سکتی ہے، ہم سب نے اپنے آپ کو دلاسہ دیا۔ اس آواز سے گفتگو متاثر ہوئی اور طالب علموں کے قہقہوں اور بات چیت کی آوازیں آنے لگیں۔ تاہم یہ سب اس وقت تبدیل ہونے لگا جب دھماکوں کی آوازیں قریب سے قریب تر ہوتی گئیں۔ میں نے سٹیج پر موجود اپنے ٹیچر سے پوچھا کہ کیا سب خیریت ہے۔ ان کا جواب تھا ‘پریشان مت ہوں، پریشان مت ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے۔’ چند طالب علم فکر مند ضرور تھے مگر دوسرے اب بھی ہنسی مذاق میں مصروف تھے۔ مگر جب ایک انتہائی زوردار دھماکہ ہوا تو پورے آڈیٹوریم میں خاموشی چھا گئی۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ اساتذہ کے چہروں پر موجود ہنسی گم ہو گئی اور انھوں نے آڈیٹوریم کے تمام دروازے مقفل کرنا شروع کر دیے۔ ایک ٹیچر نے تمام طالب علموں کو نیچے جھک جانے اور کرسیوں کے نیچے چھپنے کی تلقین کی۔ کم عمر طالب علموں نے رونا شروع کر دیا۔ میں اتنا گھبرا گیا تھا کہ سٹیج پر میں جہاں بیٹھا تھا وہیں بیٹھا رہ گیا۔ ہم میں سے کسی نے بھی اس سے قبل گولیوں کی آوازیں اتنے قریب سے نہیں سنی تھیں۔ اسی اثناء میں آڈیٹوریم کا دروازہ ٹوٹا اور یہ جنگ زدہ علاقہ بن گیا۔ گولیوں کی ترتراہٹ میں کوئی وقفہ نہیں تھا۔ وہ گولیاں برساتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ ان میں ایک نے چلا کر کہا ‘بڑی عمر کے لڑکوں کو سر میں گولیاں مارو۔’ یہ بات اس نے اتنی زور سے کہی کہ تمام لوگوں نے اس کو سنا۔ اور یہ وہ وقت تھا جب مجھے اندازہ ہوا کہ میں ابھی تک اپنی کرسی پر ہی موجود تھا۔ میں اتنا بدحواس ہو چکا تھا کہ میں اپنے جسم کو حرکت دینے سے بھی قاصر تھا۔ بیٹھا ہوا میں صرف ان کو گھور رہا تھا۔ جب ان میں سے ایک نے اپنی بندوق مجھ ہر تانی میں اس وقت بھی حرکت کرنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ مجھ سے صرف 10 میٹر کے فاصلے پر تھا جب اس نے مجھے چہرے پر پہلی گولی ماری۔ جب گولی میرے چہرے پر لگی تو مجھے بہت زیادہ درد ہوا۔ میرا منہ کھلا تھا اور اس سے خون رس رہا تھا مگر اس وقت بھی مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ حقیقت ہے۔ گولیوں کی بوچھاڑ جاری تھی۔ انھوں نے میرے دوستوں کو سر، ہاتھ، ٹانگوں اور سینے میں میری آنکھوں نے سامنے گولیاں ماریں۔ سٹیج سے میں سب کچھ دیکھ سکتا تھا۔ میں اپنے ہم جماعت طالب علموں کو اپنے سامنے مرتا ہوا دیکھ سکتا تھا۔ ان میں کچھ جلد ہی جبکہ کچھ سسک سسک کر ہلاک ہوئے۔ اگرچہ ان کے مردہ جسم میرے سامنے پڑے تھے مگر میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ میرے دوست ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور مانتا بھی کیسے چند ہی لمحوں پہلے ہم ہنس رہے تھے اور ایک دوسرے سے سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ یہ انتہائی تکلیف دہ تھا۔ میں بالکل بے بس تھا اور اس وجہ سے مکمل طور پر اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ اب میں سٹیج پر پڑا تھا اور رینگ رینگ کر یہ کوشش کر رہا تھا کہ وہاں موجود کرسیوں کے پیچھے پناہ لے سکوں۔ اسی وقت ایک دہشت گرد نے مجھے حرکت کرتا دیکھ لیا۔ اس نے میرے چہرے پر کئی گولیاں برسائیں۔ مجھے گنتی بھول گئی کہ کتنی گولیاں ماری گئیں۔ میں نے سوچا کہ سب ختم ہو چکا ہے، اور میں سٹیج کے فرش پر مرنے جا رہا تھا۔ موت زیادہ دور نہیں تھی۔ مجھے اپنے وہ تمام وعدے یاد آ رہے تھے جو میں نے اپنے والدین سے کیے تھے کہ میں ڈاکٹر بن کر ان کی زندگی میں بہتری لاؤں گا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں اب انھیں کبھی نہیں دیکھ پاؤں گا۔ آڈیٹوریم میں اب خاموشی تھی کیونکہ گولیوں میں موجود بارود کا بادل بننے کی وجہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب شدت پسندوں نے اپنی توجہ اس بات پر مبذول کی کہ آیا کوئی زندہ تو نہیں۔ انھوں نے طالب علموں کو اپنی بندوقوں کی مدد سے ہلا کر یہ دیکھنا شروع کر دیا تاکہ اگر کوئی زندہ ہو تو اسے دوبارہ گولیاں ماری جا سکیں۔ وہ مجھ تک پہنچے۔ مجھے سینے میں پاؤں سے ٹھوکر ماری جس سے میں چیخ اٹھا۔ اس نے میرے چہرے کی طرف دیکھا تو بری طرح مسخ ہو چکا تھا۔ میرا خیال ہے کہ انھوں نے مجھے اذیت ناک موت مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس انتظار کے بعد جو مجھے گھنٹوں طویل محسوس ہوا میں نے انھیں آڈیٹوریم سے واپس جاتے ہوئے سنا۔ ان کی سمت بچوں کے ونگ کی جانب تھی۔ میں نے، اپنی سانس کی گرمائش اور یہ جاننے کے لیے کہ میں زندہ ہوں، اپنا ہاتھ اپنے منہ کے سامنے رکھ لیا۔ میں زندہ تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میرا ڈھیر سارا خون ضائع ہو چکا ہے اور مجھے اپنے چہرے کا اندونی حصہ باہر ابلتا ہوا محسوس ہوا۔ مگر کسی نہ کسی طرح میں اب بھی دیکھ اور سن سکتا تھا۔ میرا دماغ کام کر رہا تھا۔ میں اب خوفزدہ بھی نہیں تھا۔ اور ایسا اس لیے تھا کہ اس سے زیادہ میرے ساتھ کیا ہو سکتا تھا؟ جب میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو ایسے کرنے میں کامیاب نہیں ہو پایا۔ میری ٹانگیں میرا ساتھ نہیں دے رہی تھیں چنانچہ میں نے رینگنا شروع کر دیا تاکہ میں اپنے آپ کو گھسیٹ کر کسی محفوظ جگہ پہنچا سکوں۔ ہر سینٹی میٹر کا فاصلہ طے کر مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسا میں درد کی وجہ سے موت کے منہ میں چلا جاؤں گا۔ اس کے بعد میں دوبارہ اپنا ہاتھ اپنے منہ کے پاس لے جا کر یہ دیکھتا کہ آیا میں اب بھی زندہ ہوں یا نہیں۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ ‘میں ابھی تک سانس لے رہا ہوں۔ جب تک میرا سانس نہیں نکلتا تب تک میں پوری کوشش کروں گا کہ میں سانس لیتا رہوں۔’ جب فوج کے ہنگامی امداد کے لوگ مجھ تک پہنچے تب تک میں 30 میٹر تک رینگ چکا تھا اور میں ہوش و حواس تقریباً کھو چکا تھا۔ میرا آدھا چہرہ ختم ہو چکا تھا اور اس بات کا تو مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ مجھے ٹانگ میں بھی گولی ماری گئی تھی۔ وہ واحد چیز جو اس دن کے حوالے سے مجھے یاد نہیں وہ یہ تھی کہ میں ہسپتال کیسے پہنچا۔ شدت پسندوں نے میرا چہرا گولیاں مار مار کر اتنا خراب کر دیا تھا کہ جب مجھے ایمرجنسی روم میں لایا گیا تو مجھے زخمیوں کے بجائے لاشوں میں ڈال دیا گیا۔ بہت سا خون ضائع ہونے کی وجہ سے میں مفلوج ہو چکا تھا۔ میں نے بولنے اور آواز نکالنے کی کوشش کی تاکہ لوگوں کو یہ بتا سکوں کے میں اب بھی زندہ ہوں مگر میرے منہ سے کوئی آواز نہیں نکلی۔ اپنے نظامِ تنفس کو جاری رکھنے کی خاطر میں نے اس امید سے لمبے سانس لینے شروع کیے کہ کسی کی نظر مجھ پر پڑ جائے۔ میرے منہ میں بھر جانے والے خون کے بلبلے بننے شروع ہو گئے۔ بعد میں مجھے بتایا گیا کہ ایک نرس نے مجھے ڈیڈ باڈیز میں ڈھونڈ نکالا۔ مجھے چہرے پر چھ جبکہ ٹانگ اور ہاتھ پر ایک ایک گولی ماری گئی تھی۔ میں پاکستان کی تاریخ کے دوسرے سب سے بڑے شدت پسندوں کے حملے سے زندہ بچ نکلا تھا۔ جن لوگوں نے ہمارے سکول کو نشانہ بنایا وہ طالبان تھے۔ حملے کا نشانہ بننے والوں میں زیادہ تر بچے تھے۔ میرے ہم جماعت جو مستقبل میں سیاستدان، انجینئیر اور ڈاکٹر بن سکتے تھے وہ چشمِ زدن میں ختم ہو چکے تھے۔ حملے کے بعد کے ابتدائی دو برس میں ہسپتال کے ایک بیڈ سے لگا رہا۔ میں کوما میں رہا اور اس کے بعد ایک آپریشن کے بعد دوسرا آپریشن۔ میرے والدین کو بتایا گیا کہ میرے بچ جانے کی صرف ایک فیصد امید ہے۔ بہت عرصے بعد جب میرے کچھ کچھ اوسان بحال ہوئے تو میں نے اپنے دوستوں کی بابت دریافت کرنا شروع کیا۔ کیا وہ زندہ ہے؟ کیا وہ ٹھیک ہے؟ میں اس دوست کو کب مل سکتا ہوں؟ ڈاکٹروں کو سب سے پہلے میرے جسم سے تمام گولیاں اور ان کے شیل نکالنے تھے۔ اور اس کے بعد انھوں نے میرے چہرے کو اکھٹا کر کے سینا تھا اور اس کے لیے کئی آپریشن درکار تھے۔ میرے سامنے کے دانت اور جبڑا مکمل طور پر ٹوٹ چکے تھے۔ چنانچہ ڈاکٹروں نے میری ٹانگ سے ایک ہڈی نکالی اور اس سے میرا نیا جبڑا بنایا گیا۔ انھوں نے میرے منہ کے اندر میٹل پلیٹس ڈالیں اور ان کی مدد سے ایک نیا جوڑ بنایا گیا۔ یہ میرے ہوئے تمام آپریشنز میں سب سے بڑا آپریشن تھا۔ جب بھی میں اکیلا ہوتا اور میرے پاس فون یا ٹیبلٹ ہوتی تو میں ہلاک ہونے والوں کے نام تلاش کرنے کی کوشش کرتا مگر اس سے قبل کے میں انھیں ڈھونڈ پاتا نرسیں یا میرے والدین مجھے ایسا کرنے سے روک دیتے۔ ہر کوئی مجھے مزید اذیت سے بچانا چاہتا تھا، اور اس کے لیے میں انھیں دوش نہیں دیتا۔ حملے کے چند مہینوں بعد میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اور جسمانی چوٹوں کی وجہ سے میں ذہنی دباؤ اور ٹراما کے باعث مفلوج ہو گیا۔ میں نے کئی مرتبہ اپنے آپ کو خود کشی کرنے کے دہانے پر پایا۔ میں نے دعا کی کہ یہ سب حقیقت نہ ہو اور میرے دوست ابھی بھی زندہ ہوں۔ ہر روز اس واقعہ کو یاد کر کے میں روتا تھا۔ کئی ہفتے ایسے ہی بیت گئے اور اس کے بعد میری والدہ میرے پاس آئیں اور انھوں نے کہا کہ ‘اب رونے سے کیا ہو گا؟ کیا تمھارے دوست ایسا کرنے سے واپس آ جائیں گے؟ مناسب یہ ہی ہے کہ تم صحت مند ہو جاؤ اور نارمل زندگی کی طرف واپس لوٹ جاؤ، اور اپنے دوستوں کے لیے کچھ ایسا کرو جس سے وہ ہمیشہ یاد رہ پائیں۔’ اس خیال نے میرے ذہن میں جگہ بنا لی۔ جب پاکستان میں ڈاکٹر میرا مزید علاج نہ کر پائے تو میرے زخموں کی پیچیدہ صورتحال مجھے برطانیہ لے آئی تاکہ مزید علاج جاری رہ سکے۔ پاکستانی فوج نے علاج میں میری مدد کی۔ یہ بہت افسوس ناک تھا کہ علاج کی غرض سے برطانیہ آنے کی وجہ سے مجھے اپنی والدہ اور بہن کو پاکستان چھوڑ کر آنا پڑا۔ جب حملے کے دو سال بعد ہم آپریشن کے لیے برطانیہ آئے تو میں اور میرے والد یہاں کسی کو نہیں جانتے تھے۔ ابتدا میں برطانیہ اور برمنگھم میرے لیے بالکل اجنبی تھے۔ جلد ہی یہاں موجود کمیونٹی نے ہمیں خوش آمدید کہا اور اب ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے برمنگھم میرے گھر سے دور میرا ایک اور گھر ہے۔ جیسے ہی میں تھوڑا بہتر ہوا تو جس بات کو میرا سب سے زیادہ جی چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ میں سکول واپس جاؤں۔ کچھ لوگوں کو شاید یہ سمجھ نہ آئے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر منطق کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو سکول وہ جگہ ہونی چاہیے جہاں مجھے سب سے زیادہ غیر محفوظ اور اداس محسوس کرنا چاہیے۔ مگر میرا خیال اس سے یکسر مختلف ہے، تعلیم وہ چیز ہے جس میں میں اپنا مستقبل دیکھتا ہوں۔ برمنگھم میں سکول جانا اچھا اتفاق تھا۔ میں بعض اوقات یہ یقین نہیں کر پاتا کہ یہاں اچھی تعلیم، امن اور انسانی حقوق ہر بچے کی دسترس میں ہیں۔ یہ سب چیزیں وہ ہیں جن کا ہم پاکستان میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ شدت پسند جو ہمارے سکول میں داخل ہوئے انھوں نے بم اور بندوق اٹھانا مناسب سمجھا، مگر اپنے ملک میں شدت پسندی کو شکست دینے کے لیے میں نے کتابیں اور قلم اٹھانا بہتر سمجھا کیونکہ میرا خیال ہے تعلیم نہ کہ اسلحہ وہ چیز ہے جس سے شدت پسند ڈرتے ہیں۔ میں اپنی اگلی سرجری کا انتظار کر رہا ہوں اور سکول بھی جا رہا ہوں۔ میں او لیول کے امتحان کی تیاری کر رہا ہوں۔ میں برطانیہ کی یوتھ پارلیمنٹ کا ممبر بھی ہوں۔ مجھے ممبر بنانے کا فیصلہ برمنگھم کے تمام سکولوں نے مشترکہ طور پر لیا تھا۔ ہم اپنے اپنے علاقے میں نوجوانوں کو درپیش مسائل کو سنتے ہیں اور سال میں ایک مرتبہ ہم انھیں ہاؤس آف کامنز بھی لے کر جاتے ہیں۔ جب برمنگھم میں اپنے نئے سکول میں اپنی بات بتانے کے لیے میں لرزتی ٹانگوں کے ساتھ سٹیج پر جا رہا تھا تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس سے بہت بڑا فرق پڑنے والا ہے۔ میں اس بات کو لے کر پریشان تھا کہ میری کہانی سن کر لوگ ہنسیں گے اور میں نے سوچا ‘کوئی میری کہانی کیوں سنے گا؟’ اس واقعے کے بعد میرا انسانیت سے یقین اٹھ چکا تھا۔ مگر جب سکول میں میں نے اپنی بات ختم کی تو میرے ہم جماعت طالب علموں نے مجھے گلے لگا لیا اور مجھے بہت عزت دی۔ انسانیت پر وہ یقین جو میں کھو چکا تھا اس کا ایک حصہ اس دن واپس آ چکا تھا۔ تب سے اب تک میں برطانیہ کے کئی سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں اور مختلف کمپنیوں کے دفاتر جا کر ترغیب دینے والی تقاریر کر چکا ہوں۔ میری ایسی ہی آخری گفتگو ’ایس او اے ایس‘ لندن میں تھی۔ میں صرف اپنے لیے نہیں جینا چاہتا بلکہ ان تمام بچوں کے لیے جینا چاہتا ہوں جو اس دن ہوئے حملے یا دیگر حملوں میں ہلاک ہوئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کے لوگ میرے دوستوں اور کلاس فیلوز کو کبھی نہ بھولیں، ان دوستوں کو جو مرنے کے لیے نہیں بلکہ پڑھنے کے لیے سکول آئے تھے۔ نئے دوست بنانا اچھا nnnnلگتا ہے مگر وہ جن کو میں کھو چکا ہوں میرے ذہن میں موجود رہتے ہیں۔
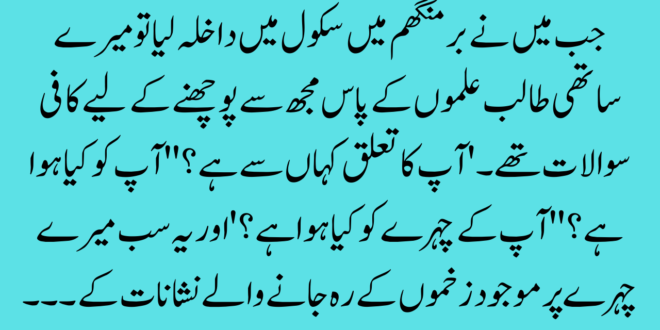
 Anmol Stories Pakistan's Best Story Website
Anmol Stories Pakistan's Best Story Website